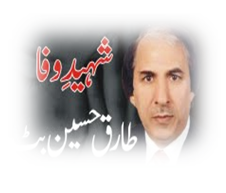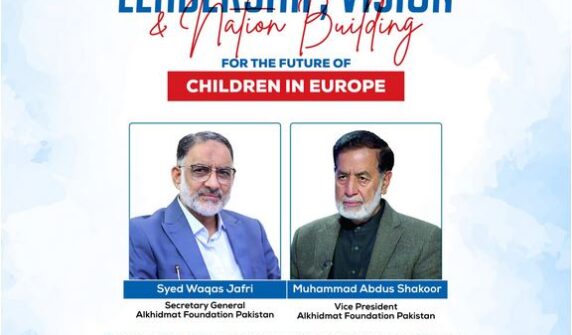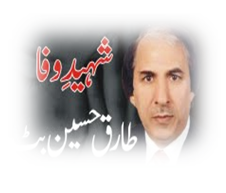
۔،۔ معراج ِ تخیل ۔طارق حسین بٹ شانؔ-،۔
انسانی پیکر روزِ ازل سے مشاہدات اور محسوسات کا خو گر رہا ہے۔جو شہ اس کے احساساتی دائرے میں مقید ہو جاتی ہے یہ اسی کے بارے میں یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟اللہ تعالی نے انسان کو خواسِ خمسہ عطا کر رکھے ہیں جو اس کائنات میں اس کی راہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں لہذا وہ انہی کی مددسے کسی بھی شہ کی ماہیت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ہمارے ہاں علم کا سب سے بڑا ذریعہ مشاہدہ ہے اسی لئے ادباء اور شعر اور علماا دور دراز کا سفر کرتے ہیں تا کہ دنیا بھر کے کلچر،رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے باقی دنیا کو اس سے روشناس کروا سکیں۔منصور حلاج،جنید بغدادی،سعدی شیرازی، ابنِ بطوطہ،کولمبس اور واسکڈے گاما اس کی سب سے بڑی مثالیں ہیں۔اب تو میڈیا اور انٹر نیٹ نے اس کائنات کو انسانی مٹھی میں بند کر دیا ہے لہذا دنیا کے بارے میں انسانی تصور بھی بدلتا جا رہا ہے۔اب ہزاروں میلوں کا جسمانی سفر طے کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ا ب انٹرنیٹ کی مدد سے ا نسان گھر بیٹھے ہر شہ سے مستفیذ ہو سکتا ہے۔یہ سچ ہے کہ خواسِ خمسہ رکھنے کے باوجود انسان فلسفیانہ مباحت اور گنجلک گتھیوں کو سمجھنے سے قاصر ہو تا ہے کیونکہ اس کی کی شعور ی سطح اس کا ساتھ نہیں دیتی لہذا ضروری ہے کہ انسان کا ادراک بھی بلند و بالا اور گہراہو بتا کہ وہ منطق کی گہری رمز کو سمجھ سکے۔ اس وقت بات مشاہدے کی نہیں بلکہ ذہنی سطح کی ہو رہی ہے جس سے محرومی کی صورت میں انسان حقائق کا مکمل ادراک نہیں کر سکتا۔ حواسِ خمسہ،تجربات اور مشاہدات انسانی فہم کو بلا واسطہ متاثر کرتے ہیں اور جو کوئی عقل و دانش اور فہم و فراست کیلئے اپنی زندگی کے شب و روز وقف کر دیتا ہے اس کا ثمر پاتا ہے۔اب اگر خواسِ خمسہ کا عطا شدہ خدائی تحفہ انسان سے چھن جائے تو اس کی کیفیت کیا ہو گی اس کیلئے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں۔،۔(تھی اندھیروں میں بھٹکی ہو ئی زندگی اور جینے کا کوئی سہارا نہ تھا)والی کیفیت ہو جائے گی۔،۔چاند ستارے،ندی نالے،دریا سمندر،پہاڑ،پھول،ابر،گلستان،بارش، بہارکہکشاں،سنگ و خشت، جگنو،خوشبو،اشجار اور طیو اور اس طرح کی ادبی تشبیہات ہیں جن سے شعرا اور ادباء اپنی بات کو زیبائی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری تشبیہات انسانی خو اسِ خمسہ سے تعلق رکھتی ہیں اور انسان انہیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ کر خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ میر تقی میرؔ کا لطیف انداز دیکھئے (نازکی اس کے لب کی کیا کہیے۔،۔ پنکھڑی اک گلاب کی سی ہے) غالبؔ کا دلفریب انداز ملاخظہ ہو۔ (ظلمت کدہ میں میرے شبِ غم کا جوش ہے۔،۔اک شمع ہے دلیلِ سحر سو خاموش ہے) قتیل شفائی یوں گویا ہوتے ہیں۔ (حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں۔،۔ ان کی صورت جو نظر آئے تو غزل کہتے ہیں)۔احمد فرازکا انداز۔(اب کے ہم بچھڑے تو شائد کبھی خوابوں میں ملیں۔،۔جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں)۔۔فیض احمد فیض (یہ ہمیں تھے جن کے لباس پر سرِ راہ سیاہی لکھی گئی۔،۔یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سرِ بزمِ یار چلے گے)۔احمد یم قاسمی کا انداز۔(انداز ہو بہو تیری آوازِ پا کا تھا۔باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔،۔(اس رشتہ لطیف کے اسرار کیا کھلے۔،۔ وہ سامنے تھا اور تصور خدا کا تھا)۔،۔ایک دلکش انداز دیکھئے۔ (تنہائی کے نازک لمحوں میں کچھ تم ہی ستارو بات کرو۔،۔ تم نے تو وہ شب دیکھی ہو گی جس کی سحر ہو جاتی ہے)۔،۔ادب میں محسوسات کی اہمیت ہوتی ہے لہذا شعرا نے سدا اس کا سہارا لیا ہے۔اب اگر کوئی ایسی بات کی جائے جو محسوسات کی زد میں نہ آئے تو اس سے قاری کس طرح لطف اندوز ہو گا؟تخیل کو لطافت کی چاشنی عطا کرنے کیلئے ضر وری ہے کہ کوئی ایسا دلکش انداز اپنایا جائے جسے پیکرِ خاکی تسلیم کر لے۔ پیکرِ خاکی کو گواہی کے بغیر تخیل محض تخیل ہی رہے گا اسے پذیرائی نہیں مل پائیگی۔اب اگر انسان کے سامنے کوئی مادی مثال نہ ہو تو وہشاعر کی تخلیق شدہ کیفیت کو کیسے سمجھے گا؟پنکھڑی کو دیکھیں گے تو لب کی نازکی اور شاعر کا مطمعِ نظر سمجھ آجائیگا۔لیکن اگر کوئی شاعر کہکشاں، فر شتو ں، سیاروں، چاند ستاروں اور عرشِ عظیم پر متمکن مخلوق اور اس کے خالق سے ہم کلامی کرے اور اسے اپنی شاعری کا موضوع بنائے تو انسان اس کی تخلیق شدہ کیفیت کی تصدیق کیسے کریگا؟ کوئی تصور مشاہدہ سے ماوراء ہو جائے تواس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ایک محاکاتی کیفیت جنم لیتی ہے جو انسان کو حیرت زدہ کر دیتی ہے لیکن جس سے اس کی لطف اانگیزی متاثر نہیں ہوتی۔اسے تحیل کی انتہا ہی کہا جا سکتا ہے کہ شاعر ایک ایساہالہ تخلیق کرے جس سے قاری کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو لیکن وہ پھر بھی گواہی دے کہ شاعر جس کیفیت کو بیان کر رہا ہے بالکل سچ ہے۔شاعری میں اس طرح کی محاکاتی کیفیت کو پید اکرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو تا ہے۔علامہ اقبال نے شکوہ کے بعد خود کلامی کا سہارا لے کر شکوہ کی اہمیت کو اجا گر کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ دیکھنے کی جسارت کی کہ عرش پر اس شکوہ کے اثرات کیا ہیں؟درجِ ذیل اشعار کو پڑھنے کے بعد آپ میری بات کی گواہی دے سکیں گے کہ شاعر نے جس طرح کی کیفیت کو اپنے اشعار میں سمویا ہے انسان کیلئے ایسی ماہیت کو سمجھنا اس کے ادراک سے بالاتر ہے۔کیا کوئی انسان اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ شاعر نے اپنے وجدان سے جس تصوراتی کیفیت کو تخلیق کیا ہے اس میں شاعر کی ذات کا کمالِ فن مضمر ہے؟پیرِ گردوں سے شاعر کا مکالمہ، اس پر کہکشاں کی گواہی،چاند کی حیرانگی اور پھر فرشتوں کا اصرار سب تخیل کی معراج ہے اور ایسا کمال اقبا لؔکے علاوہ کوئی دوسرا شاعر کر نہیں سکتا۔علامہ اقبالؔ نے ربِ ذولجلال سے شکوہ کیا تو اس کی آواز فضاؤ ں کو چیرتی ہوئی مالکِ ارض و سماء تک جاپہنچی۔فلک پر ایک ہلچل مچ گئی جس سے شکوہ کی اثر انگیزی کو بآسانی سمجھا جا سکتاہے۔حد تو یہ ہے کہ خود خدا کو اقبالؔ کے شکوہ کا جواب دینا پڑا جس سے جوا بِ شکوہ ادب کا ایک لافانی شہ پارہ بن گیا جس کی اردو ادب میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دیکھئے شاعر آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔خدا سے ہم کلامی کا مقام ہے لیکن آواز میں ایسا عزم جھلک رہا ہے کہ عرش والے بھی حیران و پریشان ہیں کہ یہ کون ہے جو عرش کے کنگرے ہلا رہاہے اور جس کی تصدیق خود مالکِ کون و مکاں کر رہا ہے۔شاعر کی جراتِ رندانہ تو دیکھئئے کہ وہ ایک ایسا دعوی کر رہا ہے جس کی تصدیق کا کوئی پہلو انسانی دسترس میں نہیں ہے۔پیکرِ خاکی کیسے تصدیق کرے کہ شاعر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے لیکن اس کے باوجود شاعر کی بلند خیالی اور اس کی دور نگاہی پر سر بھی دھنتا ہے۔اہلِ نظر اسے تخیل کی معراج سمجھتے ہیں۔آپ بھی آواز کی اثر پذیری کو محسوس کیجئے اور وجد میں آ جائیے کیجئے اور شاعر کی بلند خیالی کی داد دیجئے۔،۔(پیرِ گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی۔،۔ بولے سیارے سرِ عرشِ بریں ہے کوئی)۔،۔(چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمیں ہے کوئی۔،۔کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی)
(تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا ۔،۔عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا)۔،۔(تا سرِ عرش انسان کی تگ و تاز ہے کیا۔،۔ آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا)(آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا۔،۔ اشکِ بے تاب سے لبریز ہے پیما نہ تیرا)۔،۔(آسماں گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا۔،۔ کس قدر شو خ زبان ہے دلِ دیوانہ تیرا)۔،۔